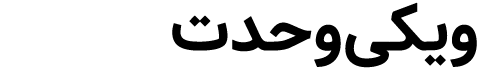تفسیر ابن بادیس
| تفسیر ابن بادیس | |
|---|---|
 | |
تفسیر ابن بادیس، جو کہ "مجالس التذکیر من کلام الحکیم الخبیر" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک اہم قرآنی تصنیف ہے جو کہ الجزائر کے عالم دین اور مصلحِ معاشرہ، عبد الحمید بن محمد بن مصطفی بن بادیس قسنطینی، جو کہ ابن بادیس کے نام سے مشہور ہیں، نے تالیف کی ہے۔ یہ تفسیر عربی زبان میں ہے اور اس میں قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ ابن بادیس نے اس تفسیر میں مختلف تفسیری طریقوں، جیسے کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر، قرآن کی سنت سے تفسیر، اور اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اقوال سے بھی استفادہ کیا ہے۔ تفسیر ابن بادیس اپنی جامعیت، روانی اور مسائلِ روز کو زیر بحث لانے کی وجہ سے بہت سے علماء اور محققین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ یہ گرانقدر تصنیف دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور ہمیشہ سے علومِ قرآنی سے دلچسپی رکھنے والوں کے زیرِ مطالعہ اور استعمال رہی ہے۔
تفسیر ابن بادیس کی خصوصیات
سلیس اور عام فہم زبان: شیخ ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں نہایت سلیس اور عام فہم زبان استعمال کی ہے تاکہ عام لوگوں کے لیے بھی قرآن کے معانی کو سمجھنا آسان ہو۔ جامعیت: اگرچہ یہ ایک مختصر تفسیر ہے، لیکن اس میں آیات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کے معانی کو واضح کیا گیا ہے۔ اصلاحی پہلو: شیخ ابن بادیس ایک مصلح تھے اور ان کی تفسیر میں بھی ان کے اصلاحی افکار کی جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے آیات کی تفسیر کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کی فکری رہنمائی کی کوشش کی ہے۔ مستند حوالوں پر مبنی: شیخ ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں قرآن و سنت کے مستند حوالوں پر اعتماد کیا ہے اور ان کے ذریعے آیات کے معانی کو ثابت کیا ہے۔
تفسیر ابن بادیس کا منہج
قرآن مجید کی تفسیر کی مختلف روشیں ہوتی ہیں ، قرآن کی تفسیر زیاده تر مفسر کے تخصص او راس کے علمی ترجیحات کے مطابق خاص جهت میں ہوتی ہے شیخ ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل منہج کو اختیار کیا ہے: تفسیر بالقرآن: انہوں نے بعض آیات کی تفسیر خود قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے کی ہے۔ تفسیر بالسنة: انہوں نے احادیث نبویہ کے ذریعے بھی آیات کی تفسیر کی ہے۔
اقوال صحابہ و تابعین: انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو بھی اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے۔ لغوی اور شرعی معانی: انہوں نے آیات کے لغوی اور شرعی معانی کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ کے لغوی اور شرعی معانی بیان کیے ہیں اور اگر ان دونوں (لغوی اور شرعی معنی) میں اختلاف پایا گیا تو شرعی معنی کو ترجیح دی ہے۔ ابن بادیس نے تفسیر طبری، کشاف، ابو حیان اندلسی اور تفسیر رازی جیسے تفسیری منابع سے استفادہ کیا ہے۔[1]
تصحیح کرنے والے کی تقریظ:
مصحح نے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے تفسیر ابن بادیس کی اہمیت اور اپنے تصحیح کے طریقے کا ذکر کیا ہے اور ابن بادیس کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تصحیح ایک علمی اور دقیق کام تھا۔ کام کی بنیاد: محقق نے اپنے کام کی بنیاد شیخ محمد البانی (متوفی ۱۴۲۰ھ) کی کتابوں پر رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصحیح حدیث کے علمی اصولوں اور قواعد کے مطابق کی گئی ہے۔ حدیث کے ذرائع: مصنف نے جن احادیث کا استعمال کیا ہے ان کے ذرائع، کتاب کا نام، باب اور حدیث نمبر کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں تاکہ قاری کے لیے ان تک رسائی آسان ہو۔ اس عمل سے تصحیح کی علمی قدر بڑھ جاتی ہے اور احادیث کی صحت کو جانچنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ رموز کا ذکر: رموز کو بغیر کسی تبدیلی کے اصلی ذرائع کی طرح ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محقق نے اپنے کام میں دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے اور متن کی اصلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔
کتابوں کے نام: کتابوں کے نام ذکر کرتے وقت، کبھی کبھار ان کے غیر مشہور ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے؛ جیسے کہ: سنن نسائی، صحیح سنن ابیداود۔ ان کے اس انتخاب کا مقصد صحیح کتابوں کو ضعیف کتابوں سے الگ کرنا تھا۔ یہ نکتہ ظاہر کرتا ہے کہ محقق، ذرائع کے ذکر میں دقت کے علاوہ ان کی صحت اور اعتبار پر بھی توجہ دیتا تھا۔ روایات اور مضامین کی فہرست: کتاب کے آخر میں روایات اور مضامین کی فہرست دی گئی ہے۔ اس سے قاری کے لیے کتاب کے مطالب تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر، ایسا لگتا ہے کہ یہ تصحیح ایک دقیق اور علمی کام ہے جو تفسیر ابن بادیس کا ایک معتبر اور قابل اعتماد نسخہ پیش کرنے کے مقصد سے انجام دیا گیا ہے۔ ذرائع کا ذکر، تصحیح کا طریقہ، اور احادیث کی صحت پر توجہ، اس تصحیح کے اہم نکات ہیں۔[2]
اقتباسات
ابن بادیس نے مقدمے میں، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد، اپنے کام کے طریقہ کار اور استعمال شدہ مصادر کی طرف اشارہ کیا ہے۔[3] مصنف نے اس یک جلدی تفسیر میں بعض سورتوں کی کچھ آیات کی تفسیر پر اکتفا کیا ہے، جن میں سورتیں مائدہ، یوسف، نحل، اسراء، مریم، طہ، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان، نمل، یٰس، ذاریات، فلق اور ناس شامل ہیں۔ عبدالحمید بن بادیس، الجزائر اور عرب و اسلامی دنیا کے معاصر دور کے بڑے دینی اصلاح پسند شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔[4] ان کے خیالات، جو دینی فکر کی تجدید اور اصلاح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے سے متعلق تھے، ان کی تفسیر قرآن میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی تفسیرِ قرآن ان کا نمایاں ترین علمی کارنامہ تھا۔ انہوں نے اپنی کوششوں کا آغاز قرآن کے حوالے سے ایک جدید نقطہ نظر پیش کرنے سے کیا۔ ان کے نزدیک وہ نظریہ، جو اسلام کو عقل کے مخالف قرار دیتا ہے اور خرافات کے ذریعے اصلاحی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ان کا مقصد قرآن کی تفسیر کے ذریعے ایسے نظریات کا مقابلہ کرنا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر ان تفاسیر کو ناقص قرار دیا جو صرف قرآن کے لغوی اور نحوی پہلوؤں یا غیر ضروری جزئیات (جیسے موسیٰؑ کے عصا کی جنس یا اصحابِ کہف کے کتے کی شکل) پر ہی توجہ مرکوز رکھتی تھیں۔ ابن بادیس کے نزدیک، قرآن جو کہ پروردگار کا انسانوں سے خطاب ہے، فردی، اجتماعی اور سیاسی زندگی میں راہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسانی زندگی کی آفات کا علاج ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ایسی تفسیر پیش کی جو دین اور سماجی و سیاسی زندگی کے باہمی تعلق کو ثابت کرتی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو، جو قرآن و سنت کے راستے کے خلاف ہو، بدعت سمجھتے تھے، جو مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن تمام مسائل کا حل اور روشنی فراہم کرنے والا چراغ ہے۔ ان کے مطابق، مسلمانوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات جهل، اسراف، ظلم، فساد اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے: "ہم پر نازل ہونے والی تمام آفات انہی راستوں سے آتی ہیں۔"[5] اسی بنیاد پر ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں اسرائیلیات کے خلاف انتباہ (تحذیر) کا طریقہ اپنایا، یعنی انہوں نے جعلی اور موضوع احادیث کے بارے میں سختی سے خبردار کیا۔ مثال کے طور پر، وہ تفسیری روایات میں جعلی احادیث کے نفوذ کے خلاف لکھتے ہیں: "حضرت سلیمانؑ کی سلطنت کی عظمت کے بارے میں بے شمار روایات نقل کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور وہ جعلی و من گھڑت ہیں، جو تفسیری کتب میں جگہ پا چکی ہیں۔" وہ خاص طور پر ان روایات پر تنقید کرتے ہیں جو کعبُ الاحبار اور وہب بن مُنَبّہ سے منقول ہیں اور سلیمانؑ کی سلطنت کو پوری زمین پر محیط قرار دیتی ہیں، جبکہ سبا (جو خود ایک عظیم مملکت تھی) حضرت سلیمانؑ کی نظر سے اوجھل رہا۔ ابن بادیس کے مطابق، ایسی روایات کا داخلی مواد ہی ان کے جعلی ہونے کا ثبوت ہے، اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ وضاحت مفسرین کو متنبہ کرنے کے لیے دی کہ وہ بغیر تحقیق کے ایسی جعلی اور متضاد (متہافت) روایات کو تفسیری عمل میں شامل نہ کریں۔[6] ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں لغوی تحقیق اور الفاظ کے معانی کی تشریح کو ایک اہم روش کے طور پر اپنایا اور بارہا اس سے استفادہ کیا۔ وہ لغت کے حوالے سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے اور قرآن کے مفردات کی توضیح میں خاص محنت کرتے تھے۔ ان کی تفسیر میں لغوی تحقیق کی مثالیں متعدد ہیں، جیسے کہ آیت "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ" (الإسراء: 12) کی تفسیر میں انہوں نے اس کے الفاظ کی وضاحت یوں کی: جعلنا اللیل..." میں "جعل" کا مطلب کسی چیز کو ایک مخصوص اور معین حالت میں رکھنا ہے۔ آیتین" لفظ "الآیة" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نشانی، علامت، دلیل اور ہدایت گر کے ہیں۔ فمحونا" کا مصدر "المحو" ہے، جس کا مطلب زائل ہونا اور مٹ جانا ہے۔[7] ابن بادیس کا یہ طریقہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کی گہرائی میں جا کر ان کے معانی کو واضح کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ آیات کی بہتر تفہیم ممکن ہو سکے۔ ابن بادیس کی تفسیر کی ایک اور نمایاں خصوصیت شعری استناد ہے، جو ان کی لغوی تحقیق کے دائرے میں ایک اہم پہلو رکھتی ہے۔ بعض مفسرین، بشمول ابن بادیس، عربی اشعار کو قرآنی الفاظ کے معانی کی وضاحت کے لیے استعمال کرنے میں بڑی وسعتِ نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اگرچہ تفسیری عمل میں شعری استناد ایک اختلافی موضوع ہے اور بعض مفسرین اسے قبول نہیں کرتے، لیکن مغربی اسلامی تفسیری روایت میں اسے ایک مستحکم اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ مثال کے طور پر، وہ آیت: "فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا" (الإسراء: 25) میں "الأوّابون" کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ "اوّابین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔" ان کے نزدیک، "الأوبة" عربی زبان میں "بازگشت" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس مفہوم کے اثبات کے لیے وہ عبید کا ایک شعر نقل کرتے ہیں: قال عبید: "وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَؤُوبُ، وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَؤُوبُ" (ہر غائب واپس آتا ہے، مگر وہ جو موت کے ذریعے غائب ہو جائے، وہ واپس نہیں آتا)[8] یہ اسلوب ظاہر کرتا ہے کہ ابن بادیس قرآنی الفاظ کی اصل معنویت کو واضح کرنے کے لیے ادبی اور لغوی روایات سے بھرپور استفادہ کرتے تھے، تاکہ الفاظ کے صحیح معانی قاری کے سامنے واضح ہو سکیں۔